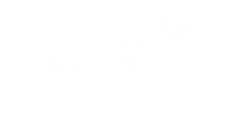عام آدمی معاشرتی زوال کی بات کرے تو سمجھ آتی ہے لیکن بہت عجیب لگتا ہے جب ادیب، سیاستدان اور صحافی ’’قحط وفا کا چرچا‘‘ کرتے دکھائی دیں کیونکہ یہی لوگ تو رائے عامہ بناتے ہیں۔ پھر معاشرتی زوال کا مطلب انکی ناکامی نہیں تو کیا ہے؟
عوام کی طرف سے گلہ بجا اس لئے کہ عوام نے اچھی سوچ اور سچ پر مبنی خیالات کو ہمیشہ خوش آمدید کہا ہے اسی لئے فیض، جالب اور منٹو آج بھی مقبولیت کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ لیکن تخلیق کاروں کے معیار بدل گئے ہیں، انکی سوچ کی وسعت بہت زیادہ حد تک پاپولرازم سے متاثر دکھائی دیتی ہے۔ آج ادب یا صحافت کے نام پر جوکچھ تخلیق ہو رہا ہے اس کے پیچھے فکری نشوونما کی بجائے ’’دام بنائے کام‘‘ والا فارمولا زیادہ کارفرما محسوس ہوتا ہے اور سیاست بھی کچھ اسی ڈگر پر مڑ گئی ہے۔ یعنی آج ہم نظریات کی بجائے الزامات کی سیاست کے دور میں جی رہے ہیں۔
معاشرتی زوال کی وجہ یہ ہے کہ نئے نظریات، اْچھوتی سوچ اور بیش قیمت خیالات کی صورت آنے والا تازہ ہوا کا جھونکا کب کا بند ہو چکا ہے جو دوائے دردِ دل بیچا کرتے تھے وہ دکان بڑھا چکے ہیں اور لگتا ہے نظریات کے نام پر سب نے اپنے اپنے مفادات کی چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول لی ہیں یہ سوچے بغیر کہ یہ عمل نئے نظریات اور سوچ کے ’’پیاسوں‘‘ کو عددی اعتبار سے کئی حصوں میں تقسیم کر کے کمزور اور پھر مایوس کر دے گا۔ اور جب درد کی دولت عام کرنیوالوں کی جگہ چمکتے سکوں کی گھن گرج لے لے گی تو معاشرہ زوال کا شکار نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟
مجھے مشہور مورخ، ادیب اور پولیٹیکل ایکٹوسٹ طارق علی کا ذوالفقار علی بھٹو کے نام خط یاد آگیا۔ بھٹو صاحب نے جب پیپلزپارٹی کی بنیاد رکھی اور سوشلزم کو معیشت قرار دیا تھا تو طارق علی نے انہیں لکھا کہ ’’ڈیئر زلفی سوشلسٹ معیشت پر تو ہماری پارٹی کتنے عرصہ سے کام کر رہی ہے اس کے لئے نئی پارٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے ہمارے والی ہی جوائن کر لو‘‘
آج پاپولرازم کا شکار ادیب، سیاستدان اور صحافی تو تھوک کے حساب سے موجود ہیں اور بقول فیض ’’اتنے کہ گِنواؤں تو گِنوا نہ سکوں‘‘ لیکن نئے نظریات اور اْچھوتے خیالات کہیں بہت ہی گہرے دفن ہوچکے ہیں۔ مجھے بابائے جمہوریت کہلائے جانیوالے انتہائی قابل احترام سیاستدان کے جملے یاد آگئے جو شاید معصومیت میں کہہ گئے تھے کہ ’’سیاسی جماعتوں کا کام اقتدار حاصل کرنا نہیں تو پھر کیا ہے؟‘‘ وہ شاید بھول گئے تھے کہ سیاسی جماعتوں کا اصل کام تن من دھن سے اپنے نظریات کا فروغ ہونا چاہئے اور اگر ان نظریات کی عوام میں مقبولیت اور قبولیت ہو جائے تو بے شک عوام اس سیاسی جماعت کو اقتدار کے سنگھاسن پر بھی بٹھا دیں تو کوئی حرج نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔ لیکن اقتدار کو ہی مرکز مان کر سیاسی میدان میں کود پڑنا نازی ازم یا فاشزم کا وطیرہ تو ہو سکتا ہے حقیقی جمہوریت کا راستہ نہیں۔
پاپولرازم کا شکار سیاست، ادب اور صحافت کا خیال آیا تو مجھے مشہور پاکستانی ادیبہ کا ایک واقعہ یاد آگیا ’’ادیبہ نے اپنی نوکرانی کو کسی کام کے سلسلے میں بازار بھیجا ’’اصولاً‘‘ اسے دس پندرہ منٹ تک آجانا چاہئے تھا لیکن وہ ایک گھنٹہ لگا آئی۔ اس پر ادیبہ نے ا س سے دیر سے آنے کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہاکہ ’’کیا بتاؤں ایک لْچا پیچھے پڑ گیا تھا‘‘ اس پر ادیبہ نے کہا کہ ’’پھر تو تمہیں اور بھی جلد آ جانا چاہئے تھا‘‘ تو وہ بولی ’’میں تو تیز چلتی تھی لیکن وہ لْچا آہستہ آہستہ چل رہا تھا‘‘ سوچنے کی بات ہے کہیں حقیقی نظریات چھوڑ کر ہم نے بھی پاپولرازم اور مراعات کے ’’لْچے‘‘ کی تال پر دھمال ڈالنا تو نہیں شروع کر دیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر کسے وکیل کریں یا کس کے پاس منصفی کیلئے درخواست دائر کریں؟ یا پھر اپنے ہی دل کو رو کر جگر کو پیٹنے کی کوشش کریں۔
انور السادات کے قتل کا ٹرائل چل رہا تھا۔ جج نے قتل کی وجہ پوچھی تو قاتل نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ ’’وہ سیکولر تھا‘‘ اور جب جج نے استفسار کیا تھا کہ ’’سیکولر کون ہوتا ہے؟‘‘ تو قاتل نے اسی معصومیت سے پھر کہا ’’معلوم نہیں‘‘ اسی طرح نوبل انعام یافتہ مصری ادیب اور صحافی نجیب محفوظ کو چھرا گھونپنے والے سے عدالت نے پوچھا ’’کیوں مارا؟‘‘ تو اس نے کہا ’’نجیب بہت متنازعہ لکھتا ہے‘‘ عدالت نے پوچھا ’’تْم نے اس کی کونسی تحریر پڑھی ہے؟‘‘ تو مجرم نے کہا ’’اس نے تو سرے سے نجیب کو پڑھا ہی نہیں‘‘ اسی طرح کہیں ہم بھی بے چراغ راہوں کے مسافر تو نہیں بن چکے۔ یہ بھی سوچنا ہے کہ جس راستے پر ہم رواں ہیں وہ راستہ ’’اندھی گلی‘‘ کہلاتا ہے یا ہم نے آنکھوں پر خودغرضی کی پٹی باندھ لی ہے؟
معاشرے کی فکری تعمیر ایک مسلسل عمل ہوتا ہے جسے کئی مشکل سوالوں کا جواب دیکر، انتہائی نامساعد حالات کا مقابلہ کر کے اور جان جوکھوں میں ڈال کر آگے بڑھانا پڑتا ہے اگر ہم سچ کے تپتے صحرا میں آرام دہ نخلستانوں کو ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے تو پھر منزل کا گلہ کئے بغیر ان ’’ریگستانوں‘‘ کی خشک ٹہنیوں پر ہی خود کو وارنے کیلئے تیار رہنا ہوگا۔
سیاست اور ادب کا کیا گلہ۔ ہماری آج کی صحافت نے بھی معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھ کر حقیقی تشخیص کی بجائے سنسنی خیزیوں کی رو میں بہنا ہی زیادہ مناسب خیال کر رکھا ہے۔ ہمیں روایتی تلقین کی جاتی ہے کہ گیس کے ذخائر اگر 2040 ء تک کافی ہوں تو یہ اس طرح نہیں کہنا کہ ذخائر اگلے 15 برس تک کافی ہیں بلکہ چیخ چیخ کر بار بار بریکنگ نیوز چلا کر بتانا ہے کہ ذخائر 2040ء میں ختم ہونے والے ہیں۔گویا ہر چیز کو منفی انداز سے دیکھنا ہی ہماری صحافت ٹھہری اسی طرح کسی صاحب نے برسوں پہلے خبر کی یہ تعریف کر دی کہ کتا انسان کو کاٹ لے تو کوئی خبر نہیں البتہ انسان کتے کو کاٹ لے تو خبر ہے۔ صحافت میں 35 برس ہونے کو آ گئے آج تک وہ انسان نہیں مل سکا جس نے کتے کو کاٹ لیا ہو اس کے برعکس کتے کے کاٹنے کی خبریں ہر دوسرے روز شائع کی ہیں اب سوچتا ہوں کہ کیا یہ درست رہنمائی ہے؟ کیا کتے کو کاٹنے والا اگر مل جائے تو اس کا اصل مقام اخبار یا چینل ہے یا پھر کوئی نفسیاتی ہسپتال؟
یہی وجہ ہے کہ ہمارے میڈیا کا زیادہ تر حصہ ”Part of Solution“بننے کی بجائے ”Part of Problem“بن چکا ہے۔بزنس، ریٹنگ اپنی جگہ لیکن سچ کے ابلاغ کا مشن نہیں بھولنا چاہئے۔ یاد رکھیں اپنے مرکز سے دور نکل جانے کا مطلب خواب ہو جانا ہے ایسا خواب جو ہستی سے نیستی کی طرف لے جاتا ہے۔
آج کی سیاست ادب اور صحافت کا حال دیکھ کر افریقہ کی ایک نو آبادی کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بار طاقت کے مظاہرے کا مقابلہ ہوا تو ’’غلاموں‘‘ نے سوچا کہ 80 سالہ انگریز آقا کو مہمان خصوصی بنانا چاہئے وہ آن بیٹھا تو کوئی نوجوان آتا اور لوہے کی سلاخ کو موڑ کر چلا جاتا۔ کسی نے ایک بار میں اتنا وزن اٹھا لیا جو عام آدمی نے ساری عمر نہیں اٹھایا ہوگا۔ انگریز وائسرائے بہت چالاک تھا یہ چالاکی اور عیاری ہی ہوتی ہے جو کسی انسان کو اپنے جیسے انسان کا آقا بننے پر اکساتی ہے یہ نو آبادیاتی آقا بھی آجکل کے سیاستدانوں، ڈرامہ نگاروں اور میڈیا پرسنز کی طرح ہر وقت ریٹنگ گرنے کے خوف میں مبتلا رہتا تھا۔ بوڑھے وائسرائے نے سوچا کہ یہاں کوئی ’’کارنامہ‘‘ نہ دکھایا تو یہ ’’غلام حقیر جان کر ڈرنا چھوڑ دینگے شاطر ذہن میں ترکیب آ ہی گئی اس نے ہتھوڑی منگوائی۔ آنکھیں بند کر کے دم سادھ لیا اور ہتھوڑے سے پہلے ایک گال تھپتھپایا پھر دوسرا اور نقلی دانتوں کا ڈنچر نکال کر اپنا ہاتھ اونچا کرکے فخریہ انداز میں یوں گھمایا جیسے اصلی دانت باہر نکال دیئے ہوں پھر وہی ہوا سب نے بے اختیار تالیاں بجا دیں۔ ریٹنگ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی اور اس مداری پن سے آقا غلام کا کھیل بھی دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔خیر فی الحال یہ سب چھوڑیں اور آئیں جالب کو یاد کرتے ہیں:
پھول شاخوں پہ کھلنے لگے، تم کہو
جام رندوں کو ملنے لگے، تم کہو…!
چاک سینوں کے سلنے لگے، تم کہو
اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لْوٹ کو
میں نہیں مانتا،میں نہیں مانتا
(حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس میں 2 فروری کو 2025ء پڑھا گیا)
Monday, May 19, 2025
کھلا جھوٹ اور ذہن کی لْوٹ

-
ٹاہلی موہری میںآپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر فوج زندہ باد ...
-
ٹاہلی موہری میںآپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر فوج زندہ باد ...
-
مارکنگ ایس او پیز پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، چیئرمین ...
-
راجہ سہیل کی طرف سے وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کے اعزاز میں ...
-
دو مبینہ ملزمان گرفتار، 10 موٹر سائیکل برآمد
-
3 اشتہاری گرفتار
ای پیپر دی نیشن
پاک افواج بازو تراتوحید کی قوت سے قوی ہے
May 19, 2025
آئی ایم ایف کی پھر حوصلہ افزا رپورٹ
May 19, 2025
بھارت کو مزید جنونیت سے روکنا اب ٹرمپ کی ذمہ داری ہے
May 18, 2025
قومی اسمبلی سے 12 بلوں کی منظوری
May 18, 2025
-
یومِ دفاع اور ملک کو درپیش سنجیدہ اقتصادی و سیاسی مسائل
-
یومِ دفاع اور ملک کو درپیش سنجیدہ اقتصادی و سیاسی مسائل
-
عوام کو ریلیف دے کر ہی خانہ جنگی کا راستہ روکا جاسکتا ہے
-
مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے
-
موجودہ حالات ملک میں فوری انتخابات کے متقاضی ہیں
-
بجلی کے بعد پٹرول بم مجبور عوام جائیں تو جائیں کہاں
ڈیجیٹل معیشت: امکانات، چیلنجز!
May 19, 2025
گوادر کے آنسو اور نااہلی کے قیدی
May 19, 2025
پاکستان کی حالیہ جنگ بندی میں اسٹریٹجک فتح!
May 19, 2025
پاک امریکا تعلقات کا نیا دور
May 19, 2025
چانکیہ ڈاکٹرائن اور بھارتی شکست فاش
May 19, 2025
تعلیم یا ہنر - ایک غلط فہمی کا تجزیہ
May 19, 2025
پاکستان میں حالیہ برسوں میں ایک غیرمعمولی مگر تشویشناک رجحان تیزی سے فروغ پا رہا ہے جسے سنجیدگی سے سمجھنے، پرکھنے اور چیلنج ...
پاک بھارت کشیدگی ''چشم دلال، جنس رسوائی''
May 19, 2025
پاک فوج کی ساکھ
May 19, 2025
موبائل فونز کمپنیوں کی لوٹ مار
May 18, 2025
پیر‘ 21 ذیقعد 1446ھ ‘ 19 مئی 2025 ء
May 19, 2025
اتوار‘ 20 ذیقعد 1446ھ ‘ 18 مئی 2025 ء
May 18, 2025
ہفتہ‘ 19 ذیقعد 1446ھ ‘ 17 مئی 2025 ء
May 17, 2025
جمعۃ المبارک ‘ 18 ذیقعد 1446ھ ‘ 16 مئی 2025 ء
May 16, 2025
جمعرات ،17ذیقعد 1446ھ15 مئی 2025
May 15, 2025
خشیتِ الٰہی (۱)
May 19, 2025
امانتداری اور روزی میں برکت
May 18, 2025
اصلاح احوال (۲)
May 17, 2025
اصلاح احوال (۱)
May 16, 2025
اسلام میں بد گوئی اور فحش کلامی کی مذمت
May 15, 2025
فرمان قائد
May 19, 2025
بحریہ پاکستان سے خطاب 23 جنوری 1948ء
May 19, 2025
فرمان قائد
May 18, 2025
ڈھاکہ … 31 مارچ 1948ء
May 18, 2025
فرمان قائد
May 17, 2025
فرمودہ اقبال
May 19, 2025
بانگِ درا
May 19, 2025
فرمودہ اقبال
May 18, 2025
ضربِ کلیم
May 18, 2025
فرمودہ اقبال
May 17, 2025
نیوز لیٹر سبسکرپشن
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: snippets/footer_view.php
Line Number: 41
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Invalid argument supplied for foreach()
Filename: snippets/footer_view.php
Line Number: 42
اشتہار
رابطہ

NIPCO House, 4 - Shaharah e Fatima Jinnah
Lahore Pakistan
Tel: +92 42 36367580 | Fax : +92 42 36367005
Nawaiwaqt Group | Copyright © 2025